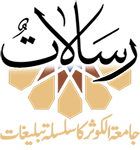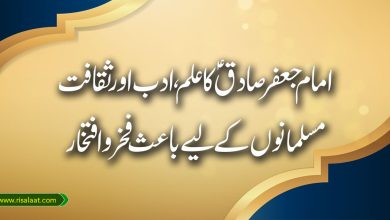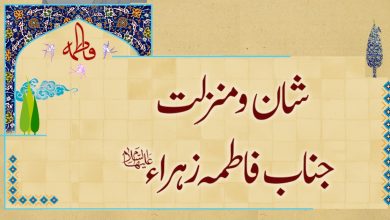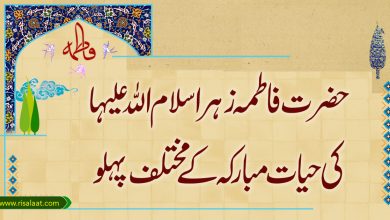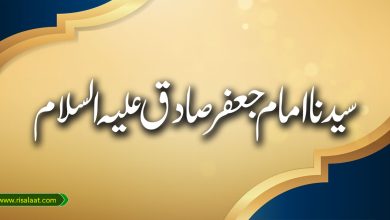حضرت امام حسین علیہ السلام سنت کے آئینے میں

(حصہ دوم)
محبت امام حسین علیہ السلام واجب ہے
کتب احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ محبت حسین علیہ السلام کے واجب ہونے کے بارے میں متواتر احادیث وارد ہوئی ہیں۔ محبت حسین علیہ السلام کسی قوم قبیلہ کے ذاتی جذبات نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے لسان وحی کے ذریعہ محبت حسین کو واجب قرار دیا گیا ہے۔
ابن عبدالبر، ابو حاتم اور محب طبری عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم فرماتے ہیں:
”من أَحَبَّنِی فَلْیُحَبَّ هٰذَینِ “
(الاصابة، ج١، ص٣٣٠۔١٧١٩؛ ذخائر العقبیٰ، ص١٢٣)
"جو مجھے سے محبت کرتا ہے اُسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے”۔
امام حسین علیہ السلام کی مدد واجبات میں سے ہے
امام حسین علیہ السلام کی محبت کی فضیلت و مذمت بغض کے علاوہ محبت حسین علیہ السلام کو واجب قرار دینے والی روایات اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کا حکم دینے والی بیشمار روایات و احادیث سے یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ اگر بعض بزرگ مسلمان حضرات حکومت یزید کو شرعی حکومت نہ سمجھتے اور مظلوم کربلا کی مدد کرتے تو آج تاریخ اسلام ہرگز مشکلات کا شکار نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کی مدد کیلئے قدم نہ بڑھانے والوں پر آج تک یہی سب سے بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل و متواتر احادیث کے باوجود انہوں نے مال و دولت یا خوف وہراس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے منہ موڑ کر یزید کے شانہ بشانہ ہوگئے۔
صحرائے کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر رکاب امام حسین علیہ السلام میں شہید ہونے والوں میں سے ایک انس ابن الحارث بن نبیہ ہیں ان کے والد بزرگوار اصحابِ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب صفہ میں سے ایک ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جبکہ حسین علیہ السلام آپ کی آغوش ِ مبارک میں موجود تھے:
”اِنّ ابْنِی هٰذا یُقْتلُ فی أرضٍ یُقالُ لها العِرَاقُ فَمَن اَدرَکَهُ فَلْیَنْصُرهُ“
(اسد الغابہ، ج١، ص ٣٤٩؛ الاصابة، ج١، ص ٦٨۔٢٦٦)
یا دکھو ، میرا یہ بیٹا سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا لہٰذا جو بھی اسے درک کرے اس کی مدد کرے۔
کنز العمال میں یہ حدیث انس بن الحارث سے ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے:
”اِنّ ابنِی هذا یُقتَلُ بأرضٍ من العراق یُقَالُ لها کربلاءَ فَمَنْ شَهِدَ ذالک مِنهُم فَلْیَنصُرْهُ “
(کنزالعمال، ج٦، ص ٢٢٣، ح٣٩٣٩)
"میرا یہ بیٹا سرزمین عراق پر کربلا میں شہید کیا جائے گا۔خوارزمی ایک طویل خبر کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، ابن عباس کے پاس آئے اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں دختر اسلام کا پارۂ جگر ہوں؟”
عرض کی : جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہی فرزند رسول ہیں اور آپ ہی کی مدد نماز روزہ و زکات کی طرح واجب ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہیں۔
فرمایا: پس اے ابن عباس اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو دختر پیغمبر کے لال کو ترک وطن پر مجبور کردے اور حرم رسوؐل، مسجد نبیؐ سے دور کردے اور انہیں اس طرح دربدر کیا جائے کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہے اور ان کی ان تمام تر سختیوں کا ہدف صرف فرزند رسول کو قتل کرنا ہو حالانکہ ان کا کوئی جرم بھی نہ ہو، نہ شرک کیا ہو اور نہ ہی خدا کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست قرار دیا ہو اور نہ ہی سیرت پیغمبؐر اور ان کے برحق جانشینوں کی مخالفت کی ہو؟
ابن عباس نے کہا: انہیں کافر ہی کہا جاسکتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ریاکاری ہے اور ان پر خدا کا بڑا عذاب نازل ہوگا۔
لیکن اے اباعبؑداللہ آپ پسر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرزند زہراء سلام اللہ علیھا ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کی مدد سے گریز کرے اور کنارہ کشی کرے گا آخرت میں اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔
یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: پروردگار گواہ رہنا۔
ابن عباس کہنے لگے: آپ پر جان قربان! گویا آپ مجھے اپنی شہادت کی خبر سنار ہے ہیں، اور مجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ خدائے یکتا کی قسم، اگرآپ کی رکاب میں تلوار اٹھاؤں اور اس قدر تلوار چلے کے ٹوٹ جائے اور میرے ہاتھ قلم ہوجائیں تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ اب بھی آپ کا حق ادا نہ کرسکا میں ابھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں آپ جو حکم دیں گے میں آپ کا مطیع و فرمانبردار ہوں۔
اسی روایت کے ضمن میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم سے سنا ہے:
”حسین مقتول فَلَئِن خَذَلُوهُ وَلَمْ یَنْصُرُوه لَیَخْذُلَنَّهُم اللّٰه اِلی یوم القیامَة“
(مقتل خوارزمی، ف١٠، ص١٩١و١٩٢)
"میرا لال حسین علیہ السلام قتل کیا جائے گا پس جس نے بھی اسے چھوڑد یا اورر اس کی مدد نہ کی تو خدا قیامت تک ان کی مدد نہ کرے گا”۔
جنت میں سب سے پہلے وارد ہونے والے
حاکم اور ابن سعد نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ان سے فرمایا:
”اِنّ اَوَّلَ مَنْ یَدخُلُ الجَنَّةَ اَنَا وَ اَنْتَ و فاطمه والحسن و الحسين قال علی: فَمُحِبُّونَا قالَ: مِن وَراٰئِکُم“
"سب سے پہلے بہشت میں ، میں، تم، فاطمہ، حسن اور حسین علیھم السلام جائیں گے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلىاللهعليهوآلهوسلم اور ہمارے چاہنے والے؟ فرمایا: وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے”۔
(صواعق ص، ١٥١؛ ذخائر العقبیٰ ص ١٢٣؛ کنزالعمال، ج٦،ص ٢١٦، ح٣٧٨٧)
طبرانی و احمد ابن حنبل نے مناقب میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔
(صواعق ص، ١٥٩؛ ذخائر العقبیٰ، ص ١٢٣؛ کنزالعمال، ج٦، ص ٢١٨، ح٣٨٢٦)
"لہٰذا اب جسے وارد بہشت ہونے کی خواہش ہے وہ دامن حسین علیہ السلام کو تھام لے”۔
امام حسین علیہ السلام اور قائم آل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم
حذیفہ، حضور سرورکائنات سے روایت کرتے ہیں کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
”لَولَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیٰا اِلّا یوم واحد لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذالک الیومَ حَتَّی یَبْعَثَ رَجُلاً مِن وُلدِی اِسمُهُ کَاِسْمِی فَقَالَ سَلْمانُ: مِں اَیِّ وُلْدِکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قال: مِن وُلدِی هذا و ضَرَبَ بِیَدهِ عَلَی الحُسَینِ “
(ذخائر العقبیٰ، ص١٣٦۔ ١٣٧)
(آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے اس سلسلہ میں ١٨٠ احادیث کتاب منتخب الاثر میں جمع فرمائی ہیں)
اگر دنیا ایک دن سے زیادہ باقی نہ رہے تو خداوند تعالیٰ اس روز کو اتنا طولانی کردے گا کہ میری اولاد میں سے ایک فرزند کو مبعوث کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔
سلمان نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ ! وہ قائم آپ کے کس فرزند سے ہوگا؟ حضور نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: میرا وہ قائم اس حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔
نام حسین علیہ السلام ۔ نام خدا سے مشتق ہے
ابو ہریرہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کے ضمن میں روایت کی ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو حضرت آدم نے عرش پر پانچ نور دیکھے جو رکوع و سجود کررہے تھے ۔ جناب آدم علیہ السلام نے سوال کیا پروردگار یہ پانچ نور جو ہیبت و صورت میں میری طرح ہیں کون ہیں؟
خطاب ہوا یہ پانچ نور تمہاری نسل سے ہیں اور ان کے نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں عالم کو خلق نہ کرتا، یاد رکھو میں محمود ہوں یہ محمد ہیں، میں عالی ہوں یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ سلام اللہ علیھا ہیں، میں احسان ہوں یہ حسن علیہ السلام ہیں، میں محسن علیہ السلام ہوں یہ حسین علیہ السلام ہیں۔
مجھے اپنی عزت کی قسم اگر کوئی ان سے ذرّہ برابر بھی کینہ و حسد رکھے گا میں اسے جہنم واصل کروں گا۔ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو تم ان سے متوسل ہونا۔
پھرپیغمبؐرنےفرمایا:ہم کشتی نجات ہیں جو اس سے وابستہ ہوجائے گا نجات پائے اور جو اس سے منحرف ہوگا ہلاک ہوجائے گا۔
(فرائد السمطین، ص ٢٥و٢٦)
امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت وکشتی نجات
ایک دن حاضرین کی موجودگی میں بزم رسالت مآب صلىاللهعليهوآلهوسلم میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو حضور سرور کائنات نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا:
”اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید“۔
حاضرین میں سے ایک صحابی جنہیں اُبَیّ بن کعب کے نام سے پہچاناجاتا ہے، نے عرض کی یا رسول اللہ صلىاللهعليهوآلهوسلم ! کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہوسکتا ہے؟
سرکار ختمی مرتبت صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا: اے اُبَیّ بن کعب، حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو آسمانوں میں زمین سے بھی زیادہ ہے، ان کا نام مبارک عرش بریں پر دائیں جانب کچھ اس انداز سے لکھا ہوا ہے:
”اِنَّ الحُسَینَ مِصْباحُ الهُدیٰ و سفینة النجاة“
"بتحقیق حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے”۔
(مدینة المعاجز، ص٢٥٩)
صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر سے کسی نے سوال کیا: ایک شخص حالتِ احرام میں مکھی کو مار ڈالتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
عبداللہ ابن عمر نے جواب میں کہا: اہل عراق پر تعجب ہے کہ مکھی کے مارنے والے کے بارے میں سوال کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے دختر رسول کے لال کو قتل کرڈالا، ( اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے) جبکہ پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلمنے فرمایا تھا:
”حسن و حسین علیہ السلام اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں “۔
(صحیح بخاری، ج ٥، ص ٣٣، کتاب فضائل الصحابه ماب مناقب الحسن و الحسین)
امام حسین علیہ السلام اورگفتار صحابہ
١۔ انس مالک کہتے ہیں: ”شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کا سر اقدس ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس نے امام مظلوم شہید کربلا کے دندانِ مبارک پر چھڑی سے جسارت کرنا شروع کردی۔۔۔ یہ بات مجھ سے کسی طرح برداشت نہ ہوئی میں نے اس کی شرزنش کرتے ہوئے کہا کہ: یہ تم کیا کررہے ہو! میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم حسین علیہ السلام کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔“
(ذخائر العقبیٰ، ص ١٢٦)
٢۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں: میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سر حسین علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد چھڑی سے لبہائے نازنین حسیؑن پر جسارت کرنے لگا، یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا: اے ابن زیاد! تو اس مقام پر چھڑی لگارہا ہے جہاں پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم بارہا بوسہ کیا کرتے تھے۔ ابن زیاد نے کہا: اٹھ جاؤ یہاں سے ! تم نے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عقل کھودی ہے۔
(کنز العمال، ج٧، ص١١٠؛ اسد الغابة، ج٢، ص ٢١)
٣۔ اسماعیل بن رجاء کے نقل کے مطابق ان کے والد کہنا ہے کہ :
میں مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کے درمیان موجود تھا جن میں ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے کہ حسین علیہ السلام ابن علی ہمارے پاس سے گزرے اور سلام کیا۔ سب نے ان کا جواب دیا لیکن عبداللہ ابن عمر سب کے خاموش ہونے تک خاموش رہے، جب سب چپ ہوگئے تو با آواز بلند کہا:
” وعلیک السلام و رحمة الله و برکاته”
پھر لوگوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگے: کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان کے نزدیک عزیز ہے؟ حاضرین نے کہا: کیوں نہیں! کہا:
وہ شخص یہ مرد ہاشمی ہے۔ جنگ صفین کے بعد انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، اے کاش اگر یہ مجھ سے راضی ہوجائے تو یہ بات میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ باعث مسرت ہوگی۔
(اسد الغابة، ج٣، ص ٥)
٤۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں:
”جو شخص اہل بہشت میں سے ایک شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم نے ان کے بارے میں یہی فرمایا ہے“۔
(نظم در رالسمطین، زرندی، ص ٢٠٨؛ البدایه و النهایه، ج٨، ص٢٢٥)
ھیثمی بھی ”مجمع الزوائد” میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:
اس حدیث کے راوی سب صحیح ہیں۔
(مجمع الزوائد، ج٩، ص ١٨٧)
٥۔عمر بن خطاب حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں:
”جو ہمارے سروں پر سایہ فگن (اسلام) ہے وہ آپ ہی کے خاندان کی بنا پر ہے۔”
(الاصابه، ج١، ص٣٣٣)
٦۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے رکاب امام حسن و حسین علیہما السلام تھام لی تو بعض لوگوں نے انہیں اس عمل پر سرزنش کی اور کہنے لگے:
آپ کی عمر ان دونوں سے زیادہ ہے ، آپ بزرگ ہیں!
ابن عباس نے فوراً جواب دیا: یہ دونوں فرزندان پیغمبراسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم ہیں کیایہ میرے لیے سعادت و شرف نہیں ہے کہ میں ان کی رکاب تھام لوں؟!
( الاصابه، ج١، ص٣٣٣)
امام حسین علیہ السلام اور تابعین
١۔ معاویہ نے عبداللہ بن جعفر سے کہا: تم بنی ہاشم کے سید و سردار ہو! انہوں نے معاویہ کے جواب میں کہا:
بنی ہاشم کے بزرگ اور سردار حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔
(کامل سلیمان، حسن بن علی ، ص١٧٣)
٢۔ولید بن عتبہ بن ابی سفیان (والی مدینہ)کومروان بن حکم نےجب امام حسین علیہ السلام کوقتل کرنےکامشورہ دیا توولیدنےکہا: "خدا کی قسم اےمروان!حسین علیہ السلام کوقتل کرکےدنیا اورمال دنیامیرے لیے بیکار ہے، سبحان اللہ کیا مشورہ دیا ہے! انہیں صرف بیعت نہ کرنے کے جرم میں قتل کردوں؟
خدا کی قسم! مجھے یقین ہےجو شخص حسین کو قتل کرے گا قیامت میں اپنے لیے وبال جان جمع کرے گا”۔
( کامل سلیمان، حسن بن علی ، ص١٧٣)
(امام حسین علیہ السلام علیہ السلام قرآن وسنت کےآئینے میں سے اقتباس)